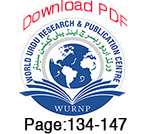محمد یاسین گنائی
پلوامہ،کشمیر
عاصیؔ فائقی کی شاعری میں صنعتوں کا استعمال
غالبؔ نے رامپور کے بارے میں کیا خوب کہا ہے’’یہ رام پورہے۔۔ دارالسرور ہے۔۔شہر سے تین سو قدم پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام ہے‘‘۔لیکن ادب کے طالب علموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنوبی ہند بھی اپنا دارالسرور رکھتا ہے اور اس کا نام’’برہان پور‘‘ اوریہ شہر دریا تاپتی کے کنارے آباد ہے،جس پر شاہجہاں نے ممتاز محل کا مقبرہ تعمیر کروایا تھا،جس کے کھنڈرات آج بھی دریا کے کنارے موجود ہیں۔شہرِبرہان پور کو’’ باب دکن‘‘ بھی کہا جاتا ہے اور یہ شہراردو کی قدیم بستیوں میں شمار ہوتا ہے۔یہاں کی علمی وادبی شخصیات کی خدمات کو منظرعام پر لانے میں’’ سیوسدن کالج برہان پور‘‘ ابتدا سے ہی کوشاں نظر آتا ہے۔ اب تک یہ تحقیقی مرکز’’برہان پور کی شعری روایات،برہان پور کے اہم مرثیہ نگار،خاندیش میں اردو شاعری کی روایت،برہان پور کی اردو شاعری پر دبستان لکھنو کے اثرات،برہان پور میں اردو نثر کا تحقیقی وتنقیدی جائزہ،برہان پور میں نظم نگاری اور اہم نظم گو شعراء،برہان پور میں اردو شعر وادب کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ،برہان پور کے اہم نعت گو شعراء اور ان کے کلام کا تحقیقی وتنقیدی جائزہ،برہان پور میں سلسلہ میرؔ ایک تحقیقی جائزہ‘‘جیسے موضوعات پر تحقیقی وتنقیدی کام کروا چکا ہے۔بہرحال اس پرانی بستی کے کچھ گمنام شعراء میں ایک نام عاصی فائقیؔ کا ملتا ہے۔عاصیؔ کی ولادت ۱۹۳۰ء میں برہان میں ہوئی تھی،والدین کی دعائوں اورعاصیؔ کی محنت سے جلدی ہی ۱۹۵۱ء میں کلرک کی حیثیت سے ملازمت ملی اور ۱۹۸۸ء میں اکاوئٹنٹ کے عہدہ سے سبکدوش ہوئے۔عاصیؔ بچپن سے ہی شعر وشاعری کا بڑا شوق رکھتے تھے،لیکن ۱۹۵۸ء سے باقاعدہ شعر وشاعری شروع کی تھی ۔وہ۱۹۶۱ء میں ڈاکٹر صلاح الدین کے شرفِ تلمذ میں شامل ہوئے تھے۔
عاصیؔکے پانچ شعری مجموعے’’طاقِ نسیاں(۱۹۸۱)،زرِ گل(۱۹۸۷)،التحیات(۱۹۸۸)،شہرخوباں(۱۹۹۰)اورشہرگل
(۱۹۹۲)‘‘منظر عام پر آچکے ہیں۔تاحال ان کی حیات وشعری کائنات پر کوئی بھرپور تحقیقی وتنقیدی کام نہیں ہواہے اور اسی سبب خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا غیر مطبوعہ کلام بھی اشاعت کے مرحلے سے نہیں گزرا ہوگا۔ عاصیؔ اپنا کلام مشاعروں میں باقاعدہ سناتے تھے اور ان کو ریڈیو سے بھی اپنا کلام سنانے کا موقع ملا تھا۔ان کو کئی انعامات واعزازات سے بھی نوازا جاچکا ہے۔لیکن ان کے کلام کو خاطر خواہ وہ پذرائی نہیں ملی ہے ۔جس کی بڑی وجہ ان کا ہجرت کرکے کھنڈوہ چلے جانا بھی معلوم ہوتاہے کیونکہ برہان پور اور بھوپال کے مقابلے میں کھنڈوہ میں اردو زبان کا اتنا زیادہ رواج نظر نہیں آتا ہے۔ ان کے خاندان،معاصرین،کلام کی خوبیاں وخامیاں،ان کے کلام کا مختلف اصناف کے تحت جائزہ اور دیگر موضوعات پر مختلف مشاہیر ادب نے بہت کچھ لکھا ہے،میری نظر میں ایک نقطہ جو ابھی تک اچھوتا نظر آتا ہے وہ ہے’’عاصیؔ کی شاعری میں صنعتوں کا استعمال‘‘کیونکہ ان کے کلام کا جائزہ لینے کے بعد اردوشاعری میں رائج متعدد صنعتوں کی مثالیں ملتی ہے۔نہ صرف عام فہم اور معروف صنعتوں کو برائے کار لایا ہے بلکہ غیر معروف وکم فہم صنعتوں کو بھی استعما ل کیا ہے۔ان کی شاعری میں تشبیہات،استعارات اور تلمیحات کا ایک بیش بہا سمندر نظر آتا ہے۔غیر معروف صنعتوں میں محاذ،مجنح،تلمیع،جمع،متتابع،
اشتقاق،رجوع،سوال جواب،جمعیت الفاظ وغیرہ کا بھی خوب سے خوب تر استعمال ملتا ہے۔ عاصیؔ نے اپنی شاعری میں تجربات بھی کیے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ شعری صنعتوں کو برائے کار لانے کا خاص ملکہ رکھتے تھے۔صنعتی شاعری میں ضروری نہیں کہ ہر شعر یا مصرعے میں صنعت پائی جائے اور نہ یہ ضروری ہے کہ ایک شعر میں صرف ایک صنعت پائی جائے۔ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی شعر میںدو تین صنعتیں موجود ہوتی ہیں۔ عاصیؔ فائقی کے کلام میں سب سے پہلے علم بیان میں شامل چار صنعتوں ’’تشبیہہ،استعارہ،مجاز مرسل اور کنایہ ‘‘ کا بخوبی استعمال ملتا ہے۔اگرچہ علم بدیع کوشبلی نعمانی نے بدعت شاعری قرار دیا ہے لیکن نجم الغنی نے’’بحرالفصاحت‘‘ میں اس تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے:
’’منفعت اس کی یہ ہے کہ کلام میں ایسی خوبی پیدا ہوجائے کہ کانوں کو بھلا معلوم ہو اور دل میں اثر کر جائے‘‘۔(بحرالفصاحت،نجم الغنی،ص:۸۹۲)
سب سے پہلے اگر تشبیہہ کا ذکر کریں تو عاصیؔ کی شاعری میں تشبیہات کا ایک دفتر کھلا ہوا نظر آتا ہے۔تشبیہہ کی اقسام اور ارکان پر نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بہترین تشبیہات کا استعمال کیا ہے۔ملاحظہ فرمائیں چند اشعار ؎
جس کے پینے سے بدل جاتی ہے دل کی کیفیت مست آنکھوں میں تمہاری کونسا مشروب ہے (طاق نسیاں،۱۷)
یہ صُراحی دار گردن،یہ نشیلی مست آنکھیں مراجامِ زُہد تقویٰ،کہیں ساقیا! نہ چھلکے (طاق نسیاں،۳۳)
حُسنِ مجسّم،نُور جہاںؔ،جوشِ محبت،سیلِ رواں دیکھا ہے اُن کو جس دم عاصیؔ،دل ہوا خود ہی شیدا شیدا (طاق نسیاں،۵۷)
یہ آنچل،یہ زُلفوں کی زرباف کرنیں یاقوسِ قزح کی حسین دھاریاں ہیں (طاق نسیاں،۷۰ )
ایک نابینا کو پیری میں عصا کا ملنا یوں ہے جیسے کوئی کھویا ہوا فرزند ملے (طاق نسیاں،۱۱۱)
ہتھیلی طشتری جس کی،وہ جس کا ہاتھ پیالہ ہے اسے مفلس نہ گردانو،وہی اللہ والا ہے (شہرخوباں،۳۰)
تمہاری آنکھ میں آنسو دکھائی دیتا ہے اندھیری رات میں جگنو دکھائی دیتا ہے (زرِگل،۶۰)
ان تشبیہات کا موازنہ اگر ہمارے قدیم اور جدید شعراء کی استعمال کی گئی تشبیہات سے کیا جائے تو عاصیؔ کے یہاں میرؔ،انیسؔؔ،غالبؔ،اقبال جیسی تشبیہات کا نظام نہ سہی بلکہ دوسری صف کے شعراء سے ملتا جلتا نظام ضرور ملتا ہے۔ان تشبیہات میں حسی ،عقلی و غیر حسی تشبیہات،ملفوف،جمع اور تفضیل تشبیہات،مفردومرکب تشبیہات،قریب وبعید تشبیہات کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔جہاں تک استعارہ کی بات ہے تو یہ تشبیہہ کے مقابلے میں زیادہ بلیغ صنعت مانی جاتی ہے کیونکہ اس میں مستعار لہ نہیں ہوتا ہے بلکہ سارا کام مستعار منہ سے چلایا جاتا ہے۔آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ تشبیہہ میں ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دیا جاتا ہے جبکہ استعارہ میں ایک چیز کو دوسری چیز مان لیا جاتا ہے۔جہاں تک عاصیؔکے کلام میں استعارات کے نظام اور ارکان کی بات ہے، تو انہوں نے اپنی بساط کے عین مطابق تشبیہات کا نادر استعمال کیا ہے۔جیسے کعبہ رخ،دل کی نظر،شام کی جھیل،سورج کا کنول،صبح عارض،انگور کا پیالہ وغیرہ ۔چند اشعار ملاحظہ فرمائیں ؎
کعبہ رُخ پہ نُور کی بارش دل کو محوِ طواف دیکھا ہے (طاق نسیاں،۲۷)
دل کی نظروں کی سبک لہروں میں غوطہ زن ہے نیلی آنکھوں کے سمندر بھی ہیں گہرے کتنے (طاق نسیاں،۳۴)
شام کی جھیل میں سورج کا کنول ڈوب چلا یعنی مُنھ موڑ کے مجھ سے مرا محبوب چلا (طاق نسیاں،۵۲)
نگہہ ناز سے اُبھری ہیں سنہری کرنیں صبح عارض کے کنول خوب سجیلے نکلے (طاق نسیاں،۷۱)
تیری آنکھوں کے چھلکتے ہوئے پیالوں کی قسم پیاس میری وہی انگور کا پانی مانگے (زرِگل،۷۹)
مجاز مرسل علم بیان کی تیسری قسم ہے اور اس میں کسی لفظ کوحقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔اگرچہ اس صنعت کو آسا ن سمجھا جاتا ہے لیکن علمائے بلاغت نے اس کی ۲۴؍ اقسام گنوائی ہے۔اس میں جنگل سے مراد درخت،خاک سے مٹی،پانی سے دریا یا سمندر مراد لی جاتی ہے۔عاصیؔ کے کلام سے چند مثالیں ؎
آنکھوں کے میکدے پہ گھٹائیں ہیں زلف کی جام وسبو ہے اور غزل کہہ رہا ہوں میں
(طاق نسیاں،۵۴)
ساون برس رہا ہے،تصورکی دھوپ ہے روتا ہوں زار زار،یہ کس کی نظر لگی (زرگل،ص:۶۹)
کنایہ سے مراد چھپا ہوااشارہ یا چھپی ہوئی بات ہے۔کنایہ کی سرحد مجاز مرسل سے ملتی ہے کیونکہ دونوں میں حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی استعمال ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کنایہ میں دونوں معنی استعمال ہوسکتے ہیں جبکہ مجاز مرسل میں صرف مجازی معنی استعمال میں لایا جاتا ہے۔بقول سجاد مرزا بیگ:
’’کنایہ لغت میں پوشیدہ بات کرنے کو کہتے ہیں اور اصطلاح علم بیان میں ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کے لازمی معنی مراد ہوں اور اگر حقیقی معنی مراد لیے جائیں تو بھی جائز ہو‘‘
تواُن کے وعدے فردا کا اعتبار نہ کر یہ دل کی بات ہے،دل میں رہی،رہی نہ رہی (طاق نسیاں،۱۱۰)
کاتبِ تقدیر نے لکھا مری تقدیر میں چندروززندگی وہ بھی پریشانی کی ساتھ (زرگل،ص:۵۹)
یوں عاصیؔفائقی کے کلام میں علم بیاں کی چاروں صنعتوں کا باقاعدہ استعمال ملتا ہے اوراس میدان کے وہ بڑے ماہر نظر آتے ہیں۔ان کی شاعری میں درجنوں دیگر صنعتوں کا بھی استعمال ملتا ہے۔ان صنعتوں کوماہر بلاغت نے صنائع لفظی اور صنائع معنوی میں منقسم کیا ہے۔دکنی دور کے شعراء کے کلام سے ہی صنعتوں کا استعمال ملتا ہے لیکن دبستان دہلی اور دبستان لکھنو کے شعراء نے اس رجحان کو بامِ عرج تک پہنچایاتھا۔حالانکہ پرانے زمانے میں استعمال ہونے والی کچھ صنعتوں کا آج رواج نہیں ملتا ہے اور مختلف تحریکات ورجحانات کے عروج کے دور ان کچھ نئی صنعتوں کا اضافہ بھی ہوچکا ہے۔ولیؔ،میرؔ ،غالبؔ،انیسؔ ،اقبال ؔسے عصرِ حاضر کے شعراء کے کلام میں صنعتوں کا ایسا بیش بہا نظام ملتا ہے کہ محقین وناقدین نے شعراء اردو کے کلام کا جائزہ صنعتوں کے استعمال کے حوالے سے لے کراس فن کورواج بخشا ہے۔عصر حاضر میں ’’صنعتی شاعری‘‘ کی اصطلاح بھی رائج ہوئی ہے،جس کے ذریعے کسی شاعرکے کلام میں صنعتوں کے استعما ل کا جائزہ لیا جاتا ہے ۔شاعری میں ان صنعتوں کے استعمال کے حوالے سے ابوافیض لکھتے ہیں:
’’صنعتیں بذات خود شاعری کا مقصد نہیں ہوتیں،لیکن شاعری کا مقصدان کے بغیر پورا بھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ذریعے شعر کے تاثر میں اضافہ ہوتا ہے‘‘۔(درسِ بلاغت، ابوافیض ،ص:۳۹)
بہرحال عاصیؔ کے کلام میں ’’صنائع لفظی‘‘ کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔یوں تو ان کے کلام میں صنائع لفظی کی کم وبیش تمام صنعتوں کا استعمال ملتا ہے،لیکن جن اہم صنائع لفظی کا استعمال باقاعدگی اور خوبصورتی سے نظر آتا ہے۔ان میں ’’صنعت تجینس‘‘سرفہرست ہے۔
’’صنعت تجنیس‘‘نہ صرف ایک قدیم بلکہ ایک معروف صنعت بھی ہے۔اس میں ایک ہی جنس کے دو یا دوسے زائد الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔اصطلاحاً اس میں تلفظ یا کتابت کے لحاظ سے مشابہت رکھنے والے الفاظ استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ یہ صنعت اتنی پیچیدہ ہے کہ علمائے بلاغت نے اس کی متضاد اقسام بیان کی ہیں۔جیسے مولوی رشید احمد نے سات،مولوی سید حامد علی نے نو،جلال الدین احمد جعفری نے بارہ،کسی نے تین، تو کسی نے دس اقسام بیا ن کی ہیں۔بہر صورت عاصیؔ کے پانچوں شعری مجموعوں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد متنوع اقسام کی تجنیس ملتی ہے۔جیسے
عشق میں فتح بھی مہنگی پڑی دیوانے کو کتنے سرہوگئے سر،آپ کے سر ہونے تک
(طاق نسیاں،۱۰۵)
قید غم سے بھی رِہا ہو کے رَہا میں ناکام دست پا میں مرے زنجیر پڑی ہو جیسے (شہرخوباں،۳۲)
ہوجائیں ایک دم میں یہ دم بازیاں تمام ہم اس کا نام لے کے اگر کردیں دم ابھی (شہرخوباں،۳۸)
دل کے غنی تھے ہم جو نہ زردار ہوسکے بے زر تھے،بے ضرر بھی تھے،بے بال وپر نہ تھے (زرِگل،۳۷)
پھر دست جنوں میں میں قلم دیکھ رہا ہوں پھر گھر سے نظر آئے گا تصویر کا کاغذ (زرِگل،۶۲)
یوں عاصیؔ کے کلام میں تجنیس کی متنوع اقسام ملتی ہیں جن میں خصوصی طور پر تجنیس تام کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔’’صنعت ِاشتقاق‘‘کی عمدہ مثالیں کلاسیکی دور کے شعراء سے تاحال برابر ملتی ہیں۔اس میں شاعر کچھ ایسے الفاظ کو جمع کرتا ہے جن کا مصدر ایک ہی ہوتا ہے۔جیسے علم،عالم،معلم،معلوم وغیرہ ۔اس کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جیسے کبھی صرف مصدر اور حاصل مصدر پایا جاتا ہے اور کبھی کبھاردوسے زائد مصادر ملتے ہیں۔اگرچہ کچھ علمائے بلاغت نے اشتقاق کو تجنیس کے ملحقات میں رکھا ہے لیکن مولوی بشیر الدین مجددی نے دونوں میں نمایاں فرق بتا یا ہے۔اشتقاق کی بھی دو صورتیں پائی جاتی ہے اورعاصیؔ کی شاعری میں اکثر دو مصدر پائے جاتے ہیں۔مثلاً
دسترس موت پہ جس کو نہیں کیا مارے گا مارنے والے سے افضل ہے بچانیوالا (زرِگل،۴۱)
پینا ہے تو پھر تلخی حالات کو پی جا ہے تلخ بہت تلخ غمِ دل کی دوا دیکھ (زرِگل،۱۰۹)
’’تضمین‘‘کو صنعت کے بجائے ایک صنف کا درجہ حاصل ہے۔لیکن کچھ شعراء نے اس کو تجربے کے طور پر استعمال کیا ہے۔تضمین نگاری ایک پیچیدہ اور مشکل فن ہے۔تضمین سے مراد اپنے یا کسی دوسرے شاعرکے شعر یا مصرعے پر شعریا مصرعہ لگانا ہے۔حالانکہ علمائے بلاغت نے اس کی متعد د اقسام گردانی ہیں جن میں مصرعے پر مصرعہ لگانا، شعر پر مصرعہ لگاکر مثلث بنانا،شعر پر شعر لگاکر مربع بنایا یا پھر شعر پر تین مصرعے لگا کر مخمس بنانا۔لیکن جب ہم عاصیؔ فائقی کے کلام کا جائزہ لیتے ہیں تو ان اقسام کے علاوہ ایک شعر پر تین مصرعے لگانا اور شعر کے دومصرعوں کے درمیان اپنی طرف سے دو مصرعے جوڑنا جیسی اقسام بھی شامل ہے۔ ان کی تضمین کی ایک خوبی یہ ہے کہ نامور شعراء کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کے کم معروف شعراء کے اشعار پر بھی تضمین لکھی ہیں۔ملاحظہ فرمائیں چند اشعار ؎
غمِ عشق کی نہ پوچھو،یہ ازل سے ہے مقدّر ’’نہ گلہ ہے دوستوں کا، نہ شکایتِ زمانہ‘‘ اقبال(طاق نسیاں،۴۵)
شب غم کی زلفوں کے سائے بڑھادیں ’’کہو تو ستاروں کی شمعیں بجھا دیں‘‘ (اختر شیرانی)(زرِگل،۳۲)
محوِ خرامِ ناز ادائیں،شباب تھا ’’وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا‘‘ (لالہ مادھو رام جوہر)(زرِگل،۵۴)
سازِ حیاتِ نو سے نئے پن کی دُھن لئے اشکوں سے صبر وضبط کے آئین سُن لئے
جس سے بھی لیں تو خوبیاں لیں،چھے گُن لئے ’’موتی سمجھ کے شان ِ کریمی نے چُن لئے
قطرے جو تھے مرے عرقِ انفعال کے‘‘ اقبال(التحیات،۱۰۱)
نزہت برگِ خوش نما کہیے نعمتِ حسن بت بہا کہیے
اور کیا اس سے کھ سوا کہیے نازکی ان کے لب کی کیا کہیے
پنکھڑی اک گلاب کی سی ہے (میرؔ،(شہرگل،۱۳۴)
خیر تسلیم،وعدہ فردا پوچھنا یہ ہے،مانیے نہ برا
گفتگو کا ثبوت کیا ہوگا تم مرے پاس ہوتے ہوگویا
جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا (مومنؔ،(شہرگل،۱۲۵)
’’صنعت تشطیر‘‘ تضمین ہی کی ایک قسم ہے ۔اس کا اصول ہے کہ کسی شاعر کے شعر کے دومصرعوں کے درمیان اپنی طرف سے دو مصرعے موزوں کئے جائیں۔عاصیؔ نے باقاعدگی کے ساتھ اس صنعت کا استعمال کیا ہے۔انہوں نے آتشؔ،حسرتؔ موہانی،اقبالؔ،سیمابؔ
اکبر آبادی،جگر ؔمرادآبادی،تاجؔ بھوپالی،شجاع خاورؔ دہلی اور دیگر شعراء کے کلام پر تشطیر لکھی ہیں۔ملاحظہ فرمائیں چند اشعار ؎
سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا؟ تیرا طریقِ کار ہے یہ خسروانہ کیا؟
کیوں اس طرح سے عمر بسر کررہا ہے تو؟ ’’کہتی ہے تجھ تو خلقِ خدا غائبانہ کیا؟ (آتش،(شہرگل،۱۲۵)
پھول کی پتی سے سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر گفتگو کیجئے مخاطب سے سمجھ کر،سوچ کو
بات کے تیور سمجھ لیتا ہے دانا آدمی مردِ ناداں پہ کلامِ نرم ونازک بے اثر (اقبال،(شہرگل،۱۲۷)
ہم کو مٹا سکے،یہ زمانے میں دم نہیں وہ ہم سے کم نہیں ہے تو ہم اس سے کم نہیں
اس کی ستم ظریفیاں ہم سے نہ چُھپ سکیں ’’ہم سے زمانہ خود ہے،زمانے سے ہم نہیں‘‘ (جگر،(شہرگل،۱۲۵)
عاصیؔ کی صنعتی شاعری کا بغور مطالعہ کرنے سے ایک بات واضح ہوجاتی ہے کہ وہ اپنے عہد اور اپنے علاقے کے ایک قابل قدر شاعر گزرے ہیں۔ان کے کلام کی جملہ خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر شیخ فرید لکھتے ہیں:
’’برہان پور کے شعراء کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ انہوں نے جدید رنگ کو اختیار کرتے ہوئے بھی قدیم روایت کا لحاظ رکھا ہے۔عاصیؔ کے کلام کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ روایتی طرز اور قدیم مسلک کے شاعر ہیں۔ ان کے کلام میں ماضی کے فکر وفن کی تمام روایات کا احترام پایا جاتا ہے۔انہوں نے اپنے جذبات کے اظہار میں روایت کے سررشتہ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔اُن کے یہاں کلاسیکی رچائو ہے،
نفاست،سلاست اور برجستگی ہے۔فنی لوازم کا التزام ہے۔وہ عصرِ حاضر کے تقاضوں سے بھی باخبر ہیں۔وہ عصری حالات وواقعات کو بیان کرتے ہیں اور فن کی روایت کو بھی روا رکھتے ہیں۔زبان وبیان کی نزاکتوں سے آگاہ ہیں‘‘۔(زرگل،ص:۱۳)
عاصیؔ فائقی کے کلام میں صنعتوں کے استعمال پر بات جاری رکھتے ہوئے ’’صنعت تکرار‘‘ کاذکر کرتے ہیں۔’’صنعت ِتکرار‘‘ایک عام فہم اور قدم زمانے سے چلی آرہی صنعت ہے۔اس میں الفاظ کی تکراراس حد تک ہوتی ہے کہ ایک ہی لفظ یا ایک جیسے الفاظ بار بار شعر میں دہرائے جاتے ہیں۔نجم الغنی نے اس کی سات اقسام بتائی ہیں اور لکھا ہے کہ اس میں دو لفظوں کو جو ایک ہی معنی رکھتے ہوں مصرعوں یا شعر میں برابر جمع کیا جاتا ہے۔عاصیؔ کے کلام سے بالترتیب تکرار مطلق اورتکرار مثنیٰ کی مثالیں پیش کرتے ہیں ؎
نہیں نکلی،نہیں نکلی،رگِ دل سے نہیں نکلی خلش پروردہ یادِ نازنیں پردہ نشیں نکلی (طاق نسیاں،۳۷)
ایسی باتیں آخر کب تک اِس کو اُس کی،اُس کو اِس کی (طاق نسیاں،۴۸)
رنگ برنگی ہلکا ہلکا،شانوں پہ آنچل ڈھلکا ڈھلکا چہرہ سیمیں اُجلا اُجلا،سینہ زریں اُبھرا اُبھرا (طاق نسیاں،۵۷)
جلوہ جاناں عُریاں عُریاں،اُلفت یاراں پنہاں پنہاں شورشِ محشر دل کی دھڑکن،سینے میں ارماں توبہ توبہ(طاق نسیاں،۵۷)
داستان گوئی کی ایک عام اور خاص خوبی’ بات سے بات نکالنا‘ ہوتا ہے۔ اگر داستانوں میں یہ خوبی نہ ہوتی تو مشکل سے ہی کوئی لمبی داستان تیارہوجاتی۔داستان کی اسی خوبی کو شاعری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے،چونکہ شاعری میں بات اعجاز واختصار کی متقاضی ہوتی ہے۔ شاعری میں بات سے بات نکالنے کا ہنر چاول پر قُل اللہ لکھنے جیسے کام ہوتا ہے۔ہمارے کلاسیکی شعراء کے ساتھ ساتھ جدید دور کے شعراء نے بھی اس چیز کو بروائے کار لایا ہے ۔ صنعتی شاعری میں اس ہنر کا نام’’صنعت متتابع‘‘ ہے۔کیونکہ اس میں دوسری بات پہلی بات کی اتباع میں لکھی جاتی ہے۔عاصیؔ کی شاعری میں اس قسم کی نادر صنعتوں کا بخوبی استعما ل ملتا ہے۔مثلاً
یہ انگ انگ مستی،مستی میں اک نشہ سا وہ بھی شباب آور،خانہ خراب کا سا (شہرخوباں،۳۱)
ہر زخم ایک پھول ہے،ہر پھول اک بہار گلشن کھلا ہوا ہے،دل داغدار میں (شہرخوباں،۸۰)
گیسوئے اختلاف کو سُلجھائوں کس طرح سُلجھایا روز روز تو وہ الجھا روز روز (زرِگل،۳۸)
غزلیں دُھن پر سنتے ہیں سنتے ہی سر دھنتے ہیں لیتے ہیں اب دلچسپی سازوں اور گانوں میں لوگ (زرِگل،۴۲)
اک کلی پھول بنی،پھول سے مہکے گلشن دفعتاً ہوگئے خوشبو سے معطر کتنے (شہرِگل،۵۷)
’’صنعت ِمجنح‘‘کوایک عمدہ اور نرالی صنعت کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں شاعر جان بوجھ کرمصرعے کی شروعات جس لفظ سے کرتا ہے،اسی لفظ سے مصرعے کا اختتام بھی کیا جاتا ہے۔اکثرو بیشتر یہ صنعت مطلع میں نظر آتی ہے لیکن شاعر زندہ دل ہو تو مطلع کے بغیر بھی اس قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔یہ صنعت ’’ردالعجز علی الصدور‘‘ سے ملتی جلتی ہے کیونکہ دونوں میں ایک لفظ کو شعر یا مصرعہ کے آغاز واختتام پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی مصرعے کے آغاز واختتام پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے،جیسے عاصیؔ فائقی نے درجہ ذیل شعر میں استعمال کیا ہے ؎
بول رہا تھا میٹھے بول اُڑ گیا پنچھی ٹوٹی ڈال (زرِگل،۹۶)
’’صنعتِ مجنح‘‘سے ملتی جلتی ایک صنعت’’ محاذ‘‘ کے نام سے رائج ہے۔ صنعتِ مجنح اور صنعت محاذ لگ بھگ ایک ہی قسم کی صنعت ہے کیونکہ دونوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ مجنح میں شعر کا پہلا اور آخری حرف ایک ہی ہوتا ہے جبکہ محاذ میں پہلے مصرعے کا آخری حرف اور دوسرے مصرعے کا پہلا حرف ایک ہوتا ہے۔علمائے بلاغت کا ماننا ہے کہ اس صنعت کیلئے زیادہ اشعار کاہونا ضروری ہے کیونکہ ایک شعر میں اس صنعت کا پایا جانا ممکن نہیںہے۔اگر صرف ایک بار یہ ترتیب پائی جائے تو اس کو’’ صنعت قطار العبیر‘‘کہتے ہیں اوراگر یہ ترتیب دوتین اشعار میں مسلسل نظر آئے تو اس کو’’ صنعت محاذ ‘‘کہتے ہیں۔عاصیؔ کی نعتیہ نظم’’روشنی‘‘میں’’صنعت قطار العبیر‘‘کی ایک عمدہ مثال ملتی ہے۔
راکٹی رفتار سے بُراق بڑھ کر تھی رواں لے گئی پل میں سواری،آسماں در آسماں
آسماں سے بھی پرے،تاعرش پھر رف رف گیا عاشق ومحبوب میں باتیں ہوئیں وعدہ ہوا (التحیات،۴۹)
لب پر نہیں کب آہ،نہیں چشم تر ہے کب؟ کب غم نصیب لوگ،گُہر رولتے نہیں (شہرگل،۷۸)
’’صنعت ِذوالقوافی‘‘ سے مراد جب شاعر جان بوجھ کر یا انجانے میں شعر میں دودو قافیوں کا استعما ل کرتا ہے۔ عاصیؔ کے کلام میں مقطع میں بھی دو دو تخلص نظر آتے ہیں ۔گویا ذوالقوافی کے ساتھ وہ ’’ذوالمقطعین‘‘ کے بھی ماہر تھے۔ذوالقوافی کے سبب شعر کو دو برابر حصّوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔کبھی کبھار اس کی سرحد’’صنعت لف ونشر‘‘ کے ساتھ ملتی ہے۔ذوالقوافی کی چند مثالیں ملا حظہ فرمائیں ؎
حورِ جنّت ہے،حورِ جنّت ہے خوب صورت ہے،خوب سیرت ہے (طاق نسیاں،۴۰)
دھڑکنیںآگئیں اس طرح مرے دل کے قریب کشتیاں ٹھہری ہوں جس طرح سے ساحل کے قریب (طاق نسیاں،۱۰۷)
دیوانے بن جاتے ہیں،آکرفرزانوں میں لوگ جانے کیا کہہ جاتے ہیں،چپکے سے کانوں میں لوگ (زرِگل،۴۲)
گھائل ہوئے ہیں جس کی سنانِ ادا سے ہم منسوب ہوگئے ہیں اسی دل رُبا سے ہم (زرِگل،۷۴)
آنکھ ہرگز مری نم نہیں ہے بارِ عصیاں سے سرخم نہیں ہے کملی والے کا سایہ ہے سر پر حشر کا اب مجھے غم نہیں ہے (التحیات،۴۲)
’’صنعت ِتلمیع‘‘کو اکثر وبیشتر’’صنعت تلمیح‘‘ کے ساتھ خلط ملط کیا جاتا ہے۔حالانکہ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔تلمیع کی راہیں قدیم زمانے میں رائج’’ریختہ گوئی‘‘سے ملتی جلتی ہے۔کیونکہ دونوں میں ایک ْسے زائدزبانوں کا استعمال ہوتا ہے۔ریختہ گوئی کی شروعات حضرت امیرخسرو نے اپنے مریدوں کی خاطر کیا تھا اوروہ شاعر ی میں ایک مصرعہ اردو اور دوسرامصرعہ فارسی زبان میں لکھتے تھے۔تلمیع میں بھی دو زبانوں کے الفاظ یا رسم الخط استعمال ہوتا ہے۔اس کی دوصورتیں ہوتی ہے،پہلی صورت ’’تلمیع کثوف‘‘ کہلاتی ہے جس میں صرف دو زبانوں کا استعمال ہوتا ہے اور دوسری صورت’’تلمیع محجوب‘‘ہے جس میں دوسے زائد زبانوں کا استعمال ہوتا ہے۔گویا تلمیع کے موجد امیر خسرو ہی ہیں لیکن غالبؔ اور پھر اقبالؔ نے اس صنعت کو بام عروج پر پہنچایا تھا۔باب ِ دکن سے تعلق رکھنے والے عاصیؔ فائقی کے کلام میں تلمیع کی چند نادر مثالیں ملتی ہیں۔
پھر اَنَا الحق‘‘ کے لئے گوش برآواز ہوئے یادِ منصور دلا کر کوئی مصلوب چلا (طاق نسیاں، ۵۲)
پہنچے تری نگاہ’’اِلَیْہِ النُّشُوْر‘‘تک لیکن قدم نہ پہنچیں سرپر غرور تک (زرِگل،۸۲)
آیت بدرؐ الدُّجیٰ والّیل کی تفسیر ہے چہرہ پُر نُور کی معصومیت کا تذکرہ (زرِگل،۹۴)
برتر وبالا ہے تو
ربی الاعلیٰ ہے تو
یا الہٰی! اَلْمَدَدْ
قُلْ ھُوَ اللہ ُ اَحَدْ (التحیات،۳۳)
پیامِ روح الامین،لا الہ الا اللہ
صدائے عرشِ بریں،لا الہ الا اللہ (التحیات،۳۵)
تجھ سے ملنے کی کس کو نہیں آرزو
تجھ کو پانے کی ہر اک کرے جُستجو
کُو بہ کُو و ہے،چرچا ترا چار سُو
تَقْنَطُوْا کی کریں تجھ سے کیا گفتگو
تیری رحمت سے وابستہ لَا تَقْنَطُوا
اللہ ھُو،اللہ ھُو،اللہ ھُو،اللہ ھُو (التحیات،۳۶)
اردو شاعری میں ضرب المثل کی مثالیں ہر شاعرکے کلام میں کم یا زیادہ ملتی ہیں۔عصرحاضر میں تحقیقی وتنقیدی کام اتنا پیچیدہ ہوچکا ہے کہ کسی شاعرکے کلام میں ضرب المثل اشعار کو بھی موضوع بنایا جاتا ہے۔اردو شاعری میں ضرب المثل پر کئی کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں ۔لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ درسی کتابوں میں کہاوتوں کو سمجھانے کیلئے ضرب المثل اشعارکو بھی شامل کیا جانا چاہیے، تاکہ طالب علموں کو کہاوت یاد رکھنے میں آسانی کے ساتھ دلچسپی بھی پیدا ہو۔بہرصورت عاصیؔ فائقی کے کلام میں ضرب المثل اشعار کی کثیر تعداد ملتی ہے۔ملاحظہ فرمائیں چند اشعار میں’’برائی پہ پردہ ڈالنا،چھوٹا منہ بڑی بات،موت کا ذائقہ چکھنا،پانی پانی ہونا،ایک جاں دوقالب،اینٹ کا جواب پتھر سے دینا،جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے‘‘جیسی کہاوتوں اور محاورات کا استعمال ملاحظہ فرمائیں ؎
جو ہوسکے تو برائی پہ ڈال دو پردہ کسی کا راز،کسی پر،کبھی نہ فاش کرو (طاق نسیاں،۱۹)
یہ چھوٹا مُنھ،بڑی باتیں نہیں ہیں خُلاصہ مثنوی کا مختصر ہے (طاق نسیاں،۲۲)
موت کاچکھنا پڑے گا ذائقہ اہتمامِ زندگی کے باوجود (طاق نسیاں،۳۸)
بھڑکتے ہوئے دل کے شعلے مرے ہوئے پانی پانی ترے شہر میں (طاق نسیاں،۷۵)
اک جاں اور دوقالب عاصیؔ آدھا حصّہ ایک ہی دھڑکا (طاق نسیاں،۱۰۳)
آج کل اینٹ کا پتھر سے ضروری ہے جواب ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے (شہرخوباں،۱۷)
جب گیڈر کی موت آئے شہر کی جانب وہ جائے بھاگ رہے ہیں شہروں سے لیکن ویرانوں میںلوگ (زرِگل،۴۲)
محمد خالد عابدی نے عاصیؔ فائقی کے کلام میں’’ضرب الامثال‘‘ اور’’سہل ممتنع‘‘ کے حوالے سے لکھا ہے:
’’شہر گل‘‘ میں ضرب الامثال کے اشعار بھی ہیں۔بعض علاقائی اور عوامی لفظ اس طرح رچ بس گئے ہیں کہ عام فہم اور سہل ممتنع کے شعر خوب ہوگئے ہیں۔عاصیؔ فائقی زود گو اور سلجھے ذہن کے اور غیر متعصب معلوم ہوتے ہیں۔بالخصوص ان کے یہاں لِسانی عصبیت نہیں ہے۔وہ نہایت روانی اور فراخدلی سے اردو،ہندی اور انگریزی الفاظ کی آمیزش سے عام قاری کے ذہن میں اپنی اور اپنے شعروں کے لیے جگہ محفوظ کرلیتے ہیں۔ان کی شاعری میں اسلامی تلمیحات بہ کثرت موجود ہیں تو ہندودیومالائی اور ہندی تلمیحات بھی کم نہیں ہیں‘‘۔(زرگل،ص:۲۵)
صنائع لفظی کے ساتھ صنائع معنوی میں بھی صنعتوں کی ایک کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ صنائع معنوی وہ صنائع ہیں جن سے کلام کی معنوی خوبیاں واضح ہوتی ہیں۔علمائے بلاغت نے کلام کوبلیغ بنانے میں معنوی حسن کو خاص اہمیت دی ہے۔اس کو صنائع لفظی پر ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ اس سے کلام میں ظاہر حسن کے ساتھ بلاغت بھی پیدا ہوتی ہے۔صنائع معنوی کی پہلی اہم صنعت’’صنعت ِتضاد‘‘ہے۔یہ ایک آسان اور عام فہم صنعت ہے۔اس سے مراد شعر میں دو یا دو سے زائد متضاد الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔درس وتدریس میں جدت لاتے ہوئے چھوٹے بچوں کو متضاد الفاظ کی پہنچان کراتے وقت’’صنعت تضاد‘‘ کی مدد لی جا سکتی ہے۔اس سے بیک وقت متضاد الفاظ اور اشعار دونوں ذہن میں محفوظ ہوجائیں گے۔تضاد کی اقسام میں ایجابی اور سلبی تضاد نام کی دواہم قسمیں پائی جاتی ہیں۔عاصیؔ کے کلام میں تضاد کے ساتھ ’’صنعت تذبیح‘‘ کی مثالیں بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔اس میں متضاد رنگوں کے ذکر سے کنایہ پیدا کیا جاتا ہے۔ملاحظہ فرمائیں تضاد کی چند مثالیں ؎
با عمل نے حُکمرانی کی ہے ہر اک دور میں بے عمل جو بھی ہے وہ محکوم ہے مغلوب ہے (طاق نسیاں،۱۷)
تفریق مٹ سکی نہ کبھی درمیان کی کہتے ہیں ہم زمین کی،وہ آسمان کی (طاق نسیاں،۲۱)
وہ جو مغرب کی حسیں شام میں جا ڈوبا تھا صبح صادق وہی پھر جانبِ مشرق نکلا (طاق نسیاں،۹۷)
خدا اور ناخدا کی ضد تھی ورنہ نہیں میں ڈوبتا ساحل پہ آکے (شہر خوباں،ص:۲۷)
اندھیرے اُجالے،اُجالے اندھیرے ہم انجامِ شام وسحر جانتے ہیں (شہرخوباں،۲۴)
موت تو اک دن اے انساں! آئیگی اور لیجائیگی روتا آیا،ہنستے جانا،ہست ونیست یقینی ہے (شہرخوباں،۴۲)
مرنے کی آرزو ہے نہ جینے کی کچھ خوشی جینا بھی اک عذاب ہے مرنا بھی اک عذاب (زرِگل،۱۰۳)
’’صنعتِ مراۃ النظیر‘‘کو ایک قیمتی صنعت مانا جاتا ہے۔اس کے تحت ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے الفاظ کو شعر میں جمع کیا جاتا ہے۔اس کے تحت لائے گئے الفاظ تضاد کے علاوہ کوئی دوسرا تعلق رکھتے ہیں اوران الفاظ میں لازمی طور پر کچھ مناسبت ہوتی ہے۔اس میں شراب کے ساتھ شرابی،ساقی،میخانہ،صراحی،جام جیسے الفاظ آتے ہیں اور باغ کے ساتھ باغباں،پھول،کلی،کانٹا،گھاس،شبنم،
پنکھڑی،پوداجیسے الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ملاحظہ فرمائیں عاصیؔ کے کلام سے مراۃ النظیر کی چند مثالیں ؎
کون بتلائے گا میخانے میں رازِ مے کشی اس میں کوئی مست ہے،ابدال ہے، مجذوب ہے (طاق نسیاں،۱۷)
رندوں کی بلا نوشی بے ہوشی میں باہوشی مینا بھی سنبھالے ہیں ساغر بھی انڈیلے ہیں (زرِگل،۳۵)
نہ سایہ ہے،نہ ٹہنی پر ثمر ہے یہ موجودہ زمانے کا شجر ہے (طاق نسیاں،۲۲)
باغباں گل آشنا،گُل آشنا ہے عندلیب زینتِ گُل،رونقِ گُلزار،شبنم آشنا (طاق نسیاں،۴۴)
خوش رنگ وخوش لباس میں لگتی ہیں خوشنما پھل،پھول،پتیوں سے لدی ٹہنیاں ہمیں (زرِگل،۲۶)
کوئی ہے زیر،کوئی زبر،کوئی پیش پیش اعرابِ زندگی میں رہے سب ہی پیش پیش (زرِگل،۴۸)
گرگئے پھل،پھول اورپتّے شجر کے جھڑ گئے پیڑ پت جھڑ کی ہوا کھا کر اکیلا رہ گیا (زرِگل،۵۴)
’’صنعتِ تعلی‘‘سے مراد ایک ایسی صنعت سے ہے جب مقطع میں شاعر اپنی، اپنے کلام یا اپنے محبوب وخاندان کی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔عموماً دیکھا گیا ہے کہ شعراء نے زیادہ اپنی بڑائی اور بلندی ظاہر کی ہے۔اگرچہ مقطع میں اس صنعت کا زیادہ استعمال ملتا ہے لیکن دیگر اشعار میں بھی صنعت تعلیٰ سے مزیں اشعار ملتے ہیں۔ملاحظہ فرمائیں چند اشعار ؎
یہ ریشِ مقدس عاصیؔ کی،چہرے سے خلوصِ دل ظاہر لونُور جہاں کے پرتو میں پہچان مہیا کرتا ہوں (طاق نسیاں،۱۸)
ذہنوں سے عاصیؔ فائقی ہرگز نہ مٹ سکے خدمت میں مُنہمک ہیں جو اردو زبان کی (طاق نسیاں،۲۱)
کرتے ہیں عاصیؔ بھی کیا آراستہ جامہ تحریر کو مضمون سے (طاق نسیاں،۲۳)
عاصیؔ،ہر اک زباں پہ ترے فن کا ذکر ہے صد شُکر کامیاب تری شاعری رہی (طاق نسیاں،۶۵)
مقبولِ عام ہوگیا عاصی ؔکا یہ کلام ذرہ کوآفتاب کے جیسا شرف ملا (زرِگل،۱۸)
’’غالبؔ کی شاعری میں استہفام‘‘ اس قسم کے درجنوں موضوعات پر تحقیقی کام ہواہے۔شاعری کے ذریعے سوال کرنا ایک پرانا اور عام مشغلہ رہا ہے،لیکن ’’صنعت سوال جواب‘‘ استہفام کے مقابلے زیادہ خوبصورت صنعت ہے کیونکہ اس میں سوال بھی شاعر کرتا ہے اور جواب بھی شاعر ہی دیتا ہے۔استہفام میں شاعر سوال کرتا ہے اور قارئین سے جواب مانگتا ہے۔سوال جواب کی ایک عمدہ مثال علامہ اقبال نے نظم’’شکوہ‘‘اور ’’جواب شکوہ‘‘ لکھ کر قائم کی ہے۔تاحال اردو شاعری میں اس سے بہترین سوال جواب کی محفل نظرنہیں آتی ہے۔ جہاں تک ’’صنعت سوال جواب‘‘کا تعلق ہے تو شاعر صرف دو مصرعوں میں سوال جواب کے تمام لوازمات پورے کرتاہے۔غزل کے جن دو مصرعوں کی کلیم الدین احمد نے زبردست تنقید کی تھی،انہی دو مصرعو ں میں سوال جواب کا پورا نقشہ کھینچا جاتا ہے۔یہ سوال جواب ایک ہی مصرعے میں بھی کیا جاسکتا ہے اور پورے شعر میں بھی۔عاصیؔ فائقی کے کلام سے’’صنعت ِسوال وجواب‘‘ کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں ؎
کیا جانے کیا تلاش ہے،کس کی تلاش ہے اک جستجو ہے اور غزل کہہ رہا ہوں میں (طاق نسیاں،۵۴)
دل کیا ہے؟اک دیا ہے،وہ بھی بُجھا بُجھا سا دیتا رہوں کب تک دل کو میرے دلاسا (شہرخوباں،۳۱)
روپوش زمانے کی نگاہوں سے ہوئے کیوں؟ ہے فرد جہاں آپ کے دیدار کا مشتاق (زرِگل،۹۹)
جبہہ سائی در جاناں پہ کیا کرتا ہوں کس لئے؟کیوں؟ مرا معمول خدا ہی جانے (زرِگل،۱۰۰ )
اس میں نہیں ہے کوئی بُرا ماننے کی بات جیسا ترا سوال تھا‘ دیسا مرا جواب (زرِگل،۱۰۳)
’’صنعتِ تجاہل عارفانہ‘‘میں شاعر جان بوجھ کر انجام بننے کی کوشش کرتا ہے،حالانکہ اس انجانے پن سے شعر میں ایک خاص قسم کی لطافت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی علمائے بلاغت نے دو اقسام بنائی ہے ،ایک تجاہل عارفانہ تردید کے ساتھ اوردوم تجاہل عارفانہ بغیر تردیدکے۔عاصیؔ کے کلام سے ’’صنعتِ تجاہل عارفانہ‘‘ کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں ؎
کنارے دور ہیں،موجوں سے سر اُٹھایا ہے الہٰی کشتی دل گھر گئی بلائوں میں (طاق نسیاں،۳۲)
تراراز یہ کسی نے نہیں آج تک بھی جانا ہمیں خاک سے بنایا،ہمیں خاک سے ملانا (طاق نسیاں،۴۵)
بہاریں آگ برسانے لگیں کیا؟ شگوفے کس لیے مُرجھا رہے ہیں (شہرخوباں،۲۵)
میں اپنے آپ سے مدّت ہوئی ہے مل نہیں پایا نجانے کب فنا آئے بقا سے ملوں کب تک (زرِگل،۸۳)
ہم چل پڑے ہیں راہِ محبت میں سر کے بل کھالی ہے د ل نے چوٹ تو دیکھیں گے سر کی چوٹ (زرِگل،۱۰۷)
اردو شاعری میں استعمال ہونے والی چند بہترین اور کارگر صنعتوں میں’’صنعت لف ونشر‘‘کا ذکربھی آتا ہے۔اس صنعت میں پہلے چند چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر ان چیزوں کی مناسبت کو بیان کیا جاتاہے۔اسی وجہ سے لف ونشر کا نام دیا گیا ہے۔اس کی تین یا چار قسمیں بتائی گئی ہے۔لیکن زیادہ تر مرتب اور غیر مرتب لف ونشر ہی نظر آتی ہے۔’مرتب اور غیر مرتب لف ونشر‘‘کی چند مثالیں بالترتیب ملاحظہ فرمائیں ؎
تم پیکرِ مستی ہو،تم زینتِ مے خانہ مینا کی سی گردن ہے،آنکھیں ہیں کہ پیمانے (طاق نسیاں،۱۱۰)
تم مجسم شادمانی،ہم سراپا غم رہے تم نہ ہم سے کم رہے،ہم بھی نہ تم سے کم رہے (شہرخوباں،۵۱)
دنیا میں خودپرست ہے کوئی خدا پرست ہے آسماں بلند بہت اورزمین پست (طاق نسیاں،)
سحر جس کی نہ ہوئی ہو،نہ جس کی شام ہوئی ہو کوئی ایسی بھی شام آئے،کوئی ایسی سحر آئے (طاق نسیاں،۵۶)
کتنے ناوک چلے،کتنے خنجر چلے تیرے سر کی قسم،میرے سر کے لئے (طاق نسیاں،۸۰)
منزلِ عشق پالینا دشوار ہے،گامزن ہے جواس پروہ بیزار ہے
آج تک بھی نہ کوئی اسے پاسکا،قافلے کتنے راہوں میں گُم ہوگئے (طاق نسیاں،۵۳)
اردو شاعری کی کم معروف صنعتوں میں’’صنعت جمع‘‘ کا شمار ہوتا ہے۔اگرچہ گرائمر کی رو سے جمع سے مراد ایک سے زائد چیزوں،اشخاص یاجگہوںکے ذکر کرنے کو کہتے ہیں۔لیکن صنعتی شاعری میں ’’جمع‘‘ سے مراد کلام میں ایک ہی قید،شرط یا حکم کے تحت چند چیزوں کو جمع کرنے سے ہے۔صنعت جمع‘‘ کی سرحد کبھی کبھی مراۃ النظیر سے بھی جاملتی ہے اور کبھی اس میں ’’صنعت اشتقاق‘‘ کی خوبی نظر آتی ہے۔ عاصیؔ کے شاعری میں بھی ’’صنعت جمع‘‘ کی کچھ مثالیں ملتی ہیں۔
آپ میرے غم کے بارے میں نہ کچھ غم کیجیے غمزہ ہوں،غمزہ کو،غم فراہم کیجئے (شہرخوباں،۲۹)
شہر کے ہر فرد سے ہم آشنا،تم آشنا موت سے لیکن جہاں میں آشنا کوئی نہیں (شہرخوباں،۴۱)
کیوں مندر ومسجد کی حدیں روندرہا ہے و ہ اپنا،دل اپناہے،تو اپناہی گھر ڈھونڈ (زرِگل،۱۷)
سرمستیِ شباب کا عالم تو دیکھئے دل بھی،جگر بھی،آپ بھی،میں بھی جوان ہوں (زرِگل،۳۴)
چشم مستانہ سے حصّہ سب کو ملنا چاہیے ساقی میخانہ! میخانے کا یہ دستور ہے (زرِگل،۱۰۱)
کم معروف صنعتوں میں’’رجوع‘‘ بھی ایک دلچسپ صنعت ہے۔اس میں شاعر پہلے کسی چیز، شخص یاجگہ کی صفت یا خوبی بیان کرتا ہے اور پھر اس صنف یا خوبی سے انکار کرکے کوئی دوسری صفت یا خوبی بیان کرتا ہے،جو پہلی صفت یا خوبی کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور افضل ہو۔یہ ایک دلچسپ صنعت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشکل صنعت بھی ہے۔فائق عاصیؔ کے کلام کا بغور جائزہ لینے کے بعد اس صنعت کی چند مثالیں نظروں سے ضرور گزرتی ہیں۔
گذرے لمحوں کی طرح لوٹ کے کیا آئے گا جاکے آیا نہیں کرتا کبھی جانیوالا (زرِگل،۴۱)
آپ پوچھیں تو بتائے گی نسیم اُردو کس چمن میں نہیں دلی دکن کی خوشبو (زرِگل،۶۵)
اس کے رخِ جمیل کی تشریح کب کریں ہاتھوں کی صندکی پہ رکھی ہے کُھلی کتاب (زرِگل،۱۰۳)
کس منہ سے یہ کہتے ہو انجام نہیں اچھا یہ کام نہیں اچھا وہ کام نہیں اچھا (زرِگل،۱۰۴)
یہ یاد رہے عاصیؔ! دنیا ئے محبت میں سنتے ہیں کہ بد اچھا بدنام نہیں اچھا (زرِگل،۱۰۴)
’’صنعت حسن تعلیل‘‘مرزا غالبؔ کی پسندیدہ صنعت ہے۔اس میں شاعر کسی واقعہ یاحادثے کی وہ وجہ بیان کرتا ہے،جو اس کی اصل وجہ نہیں ہوتی ہے اور شاعر جو وجہ بیان کرتا ہے اس میں فوق الفطری عنصر کا خدشہ ہوتا ہے۔اس کی چار قسمیں پائی جاتی ہے۔عاصیؔ فائقی کے کلام سے چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں ؎
ساقیا! لُطفِ نظر ہوتو مزاآجائے خود ہی مے خانہ چلا آئے گا میخوار کے پاس (طاق نسیاں،۴۹)
موجِ دریا ہی نہیں،لمس کی خاطر عاصیؔ مچھلیاں چھونے لگیں اُن کے چرن پانی میں (طاق نسیاں،۸۱)
حسنِ اشعار کی تشکیل نرالی ٹھہری درِ جاناں کی زمیں ہو تو غزل ہوتی ہے (شہرخوباں،۱۶)
ساحل پہ سیپیاں تک رو رو پڑی ہیں دیکھو پانی میں ڈوب کر بھی کیا ہوگا کوئی پیاسا (شہرخوباں،ص:۳۱)
گل سے بلبل کو محبت ہوگئی قیمتِ گل بیش قیمت ہوگئی (زرِگل،۱۰۲)
’’صنعت تعجب‘‘میں شاعر کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جس سے قارئین کچھ دیر کیلئے تعجب کا شکار ہوتے ہیں۔یہ ایہام،ابہام اور مبالغہ کے مقابلے میں ایک الگ صنعت ہے۔چند مثالیں
عاصیؔ کو پینے دیجئے،کیجئے نہ بحث آپ پہنچے گی ورنہ بات بہت دور دور تک (زرِگل،۸۲)
شہر میں کون بسنے لگے آج کل آدمی بھی نہیں آدمی کی طرح (زرِگل،۹۵)
اردو شاعری میں جمعیت الفاظ کی طرف بطور صنعت بہت کم توجہ دی گئی ہے۔اس صنعت کے تحت شعر یا مصرعے میں شاعر متواتر کسی ایک شخصیت یا چیز کو مختلف القابات،تشبیہات یا ناموں سے یادکرتا ہے۔اس صنعت کے تحت کسی شے یا شخص کی خوبیوں سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ عام قاری الفاظ کے ایک بیش بہا خزانے سے متعارف ہوتا ہے۔جمعیت ِ الفاظ کی درجنوں مثالیں عاصی ؔ کے کلام میں جگہ جگہ ملتی ہیں۔ملاحظہ فرمائیں چند اشعار ؎
نرگسی،نیل کنول سی،یا مرگِ نینی ہوں دل پہ لاتی ہیں خرابی،یہ گلابی آنکھیں (شہرخوباں،۲۱)
دفعتاً مٹ نہ جائیں کہیں قہر سے، آسمان وزمیں، بحر وبر دیکھنا (زرِگل،۴۳)
انکساری،سادگی،دریادلی،فرزانگی تھیں بہت سی خوبیاں نواب خرقہ پوش میں (زرِگل،۶۶)
میکدے سے عجز کا پیغام ملتا ہے سدا جانبِ مینا جھکے خم،مینا ساغر کی طرف (زرِگل،۹۸)
چشم ساقی ملتفت ہے میکدہ معمور ہے جس کو دیکھو مست ہے مخمور ہے مسرور ہے (زرِگل،۱۰۱)
تیر مژگاں، تیغِ ابرو تیز تو دونوں ہی ہیں دیکھئے کس کی قضاآئی ہے کیا منظور ہے (زرِگل،۱۰۱)
سبز گنبد کا مکیں ہے وہ شفیع مُذْنِبْ امّت عاصیؔ کو دوذخ سے بچانے والا (التحیات،۴۰)
وہی ہستی کہ جس کی بشت پر مُہر نبوّت تھی امام الانبیا ٹھہری،وہ ختم المرسلیں ٹھہری (التحیات،۴۴)
؎ ’’صنعت تلمیح‘‘سے مراد جب کلام میں کسی مشہور قصے،واقعے،شخص،چیز،کردار یاروایت کا ذکر کیا جائے۔اس کی خوبی یہ ہے کہ ایک ہی لفظ سے پورا واقع یا قصّہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔تلمیحات اقبال،غالب،انیس،دبیر اور دیگر شعراء کی تلمیحات پر الگ الگ طور پر تحقیقی کام ہوچکا ہے۔عاصی کے کلام میں ہند ومسلم دونوں مذاہب کی تلمیحات پائی جاتی ہیں۔ان کے کلام میں پائی جانے والی اہم تلمیحات میں’’کوہ طور،معراج، موسیٰ،طوفان نوح،خضر،طوافِ کعبہ، سکندر،ارسطو،یوسف زلیخا،تاج محل،حضرت یعقوب،منصور‘‘وغیرہ قابل ذکر ہیں۔عنوان چستی کے بقول عاصیؔ ایک مخلص شاعر ہیں،جو سادگی اور بے ریائی اُنکی شخصیت کا جوہر ہے،وہی اُن کے کلام کا طرہ امتیاز ہے،انہوں نے شعری روایت سے زبردست استفادہ کیا ہے‘‘۔(شہرگل،فلیپ سے)ملاحظہ فرمائیں چندتلمیحات عاصیؔ ؎
وہی ہستی کہ جس کی پُشت پر مُہر نبوّت تھی امام الانبیاء ٹھہری وہ ختم الرُسلیں ٹھہری (طاق نسیاں،۱۶)
باغِ ارم کی سیر کی،باغِ جہاں کی سیر آدم کا جانشین ہوں،جنت نشان ہوں (طاق نسیاں،۲۵)
اک حُسن مجسم نظر آنے لگا مجھکو موجوں سے اُٹھا ساغرِ جمشید کا سورج (طاق نسیاں،۲۸)
بہرِ یاجوجؔ و ماجوجؔ وقت کا بن جا ذُوالقرنین (طاق نسیاں،۴۱)
اب بھی اندر ؔپرست ہیں پریاں منظرِ کوہ قافؔ دیکھا ہے (طاق نسیاں،۲۷)
پیرہن کاغذی راونؔ کے سرعام جلے ان مناظر سے بھی گذرے ہیں دسہرے کتنے (طاق نسیاں،۳۴)
کوئی موسیٰ نہیں کہ غش کھائوں اپنا رُخ بے نقاب رہنے دے (طاق نسیاں،۹۹)
عاصیؔ کا ساتھ،سرمدؔ ومنصورؔ سے رہا یہ تھے ہماری راہ کے اصحاب خاص خاص (زرِگل،۳۰)
لکشمنؔ ریکھا کو راونؔ کرسکا ہرگز نہ پار رامؔ کے ہاتھوں وہ لنکا میں سُلگتا رہ گیا (زرِگل،۵۴)
’’صنعت ِتنسیق الصفات‘‘یہ صنعت بھی ایک غیر معروف اور کم استعمال ہونے والی صنعت ہے۔ اس صنعت کے تحت شاعر کسی خاص موقع پر چند الفاظ ایک ہی وزن یا ایک ہی قسم کی پے در پے شعر میں جمع کرتا ہے جس سے شعر میں ایک خاص قسم کا لطف پیدا ہوتا ہے۔دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کسی اہم یا غیر اہم شخص یا کسی چیز کا ذکر اس کی صفات کے ساتھ کرتا ہے،اس میں خوبی اور خامی دونوں شامل ہوسکتی ہیں۔گرائمر کے حوالے ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًسے بات کریں تو صنعت تنسیقِ الصفات کسی حدتک عرف سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے۔علمائے بلاغت نے اس کو صنائع لفظی اور معنوی دونوں میں شامل کیا ہے۔اس میں کسی شخص یا چیز کی مدح یا ذم پیش کی جاتی ہے۔اس صنعت کا زیادہ تر رواج قصائد میں ملتا ہے۔فائق عاصیؔ کے کلام سے چند مثالیںملاحظہ فرمائیں۔
تو رنگ ونسب،شکل وشباہت نہ قبا دیکھ تخلیقِ الہٰی کا ذرا نشو ونما دیکھ (زرِگل،۱۰۹)
دے رہی ہے پیام کی خوشنودی میٹھی میٹھی حضور کی باتیں (طاق نسیاں،ص:۴۳)
’’سہل ممتنع‘‘ ایک قدیم صنعت ہے اور اس سے مراد ایک ایسے شعر سے ہے جس کو نثر کی طرح پڑھا جاسکتا ہے۔سہل ممتنع بظاہر آسان شعر ہوتا ہے اور دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ میں بھی ایسا شعر کہہ سکتا ہوں مگر درحقیقت ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے۔دوسری بات بقول مرزا غالب اورنجم الغنی سہل ممتنع وہ نظم یانثر ہوتی ہے جو دیکھنے میں بالکل آسان نظر آئے مگر اس کا جواب نہ ہوسکے ۔ڈاکٹر اشفاق انجم نے عاصیؔ کے کلام کے محاسن میں سہل ممتنع کو ایک اہم خوبی گردانتے ہوئے لکھا ہے:
’’جس طرح عاصیؔ صاحب کو دیکھ کر پہلی نظر میں آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ حضرت کوئی ثقہ بزرگ اور کسی دینی مدرسہ کے مدرّس ہوں گے،اسی طرح ان کی شاعری بھی نظروں کوفریب میں مبتلا کردیتی ہے۔ان کا اسلوبِ نگارش ایسا رواں دواں ہے کہ قاری پڑھتا چلا جاتا ہے۔اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور آخر میں وہ یہ فیصلہ کرلیتا ہے کہ’’دلچسپ کلام ہے‘‘ مگر وہ لوگ جو اسے رک رک کر پڑھیں گے انہیں سہل ممتنع میں ایسے بلند اشعار اور گہرے معانی نظر آئیں گے کہ طبیعت خوش ہوجائیگی‘‘۔(شہرخوباں،ص:۱۲)
عاصیؔ کے کلام سے سہل ممتنع کی چندمثالیں ملاحظہ فرمائیں ؎
دردِ دل کا سوا نہیں ہوتا تم جو چاہو تو کیا نہیں ہوتا (شہرگل،۶۲)
باعمل زندگی بھلی عاصیؔ بے عمل زندگی میں خواری ہے (شہرگل،۶۷)
ان سے الفت اگر نہیں ہوتی زندگانی بست نہیں ہوتی (شہرگل،۷۹)
زلف کے برخلاف دیکھا ہے مطلعِ حسن صاف دیکھا ہے (طاق نسیاں،۲۷)
ہندو،مسلم،سکھ یا جین ایک ہی سب کا نصب العین (طاق نسیاں،ص:۴۱)
اردو شاعری میں سراپا نگاری کے موجد وامام ولی دکنی کہلاتے ہیں۔سراپا سے مراد محبوب کی سرسے پائوں تک تعریفیں کرنا ہے۔اس میں محبوب کے ہونٹوں،آنکھوں،زلفوں،قد،چال ڈال،رخسار،پائوں وغیرہ کی تعریفیں بیان کی جاتی ہے۔ولیؔ،میرؔ،مومنؔ کو اس فن میں ملکہ حاصل ہے۔عاصیؔ کے کلام سے سراپا نگاری کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں ؎
گھنیری زلف کے جوڑے کا خوشنما منظر رخ جمیل پہ کتنا سہانا لگتا ہے (شہرخوباں،ص:۳۳)
کتنا نورانی اس کا چہرا ہے بدنگاہی کا جس پہ پہرا ہے (شہر گل،ص:۴۴)
اس نازنین کے ’پنجہ مرجاں‘ کی نازکی زریں انگوٹھیوں کے نگینے سے پوچھئے (شہر گل،ص:۴۵)
تیری آنکھوں میں یہ حیا کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں مدعا کیا ہے (شہر گل،ص:۴۹)
غرض عبدالبصیر عاصیؔ فائقی کا حلیہ اگرچہ دینی مدرسہ کے عالم وفاضل جیسا نظر آتا ہے لیکن ان کی شاعری کا مطالعہ کرنے کے بعد اس میں میرؔ کی دل لگی،مومنؔ کی سادگی،اقبالؔ کی تلمیحات،غالبؔ کا فلسفہ،چکبستؔ کی ہندی روایت اور دیگر شعراء کے کلام سے بھی اِکا دُکاخوبیاں نظر آتی ہے۔ان کاچہرہ ضرورمولوی جیسا دکھتا ہے لیکن ان کا دل جوان ،آنکھیں مست اور کلام تکلف،بناوٹ،تصنع اور آورد سے بالکل مبرّا نظر آتا ہے۔ان کی صنعتی شاعری سے ایک بات واضح ہوجاتی ہے کہ وہ آمد کے شاعر تھے نہ کہ آوردکے اور اسی سبب ممکن ہوسکا ہے کہ نئی پرانی تمام صنعتوں کا بہترین انداز میں استعمال کیا ہے۔ان کی شخصیت کے ساتھ ان کاکلام اور اس میں استعمال ہونے والی صنعتیں بھی پہلودار نظر آتی ہیں۔ اُمید کرتا ہوں عاصیؔ فائقی کے کلام پر مزید تحقیقی وتنقیدی کام ہوگا اورعلاقائی ادب کے تحت ان پر سندی تحقیقی کاکام بھی ہوناچاہیے۔عاصیؔ جیسے مزیدگمنام شعراء پربھی تحقیقی وتنقیدی کام ہونا چاہیے تاکہ اردو زبان وادب کا دائرہ مزید وسیع ہواوران شعراء کا کلام بھی ادبی حلقوں تک پہنچ سکے۔
***